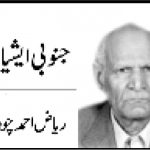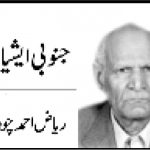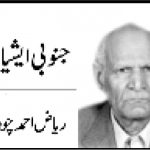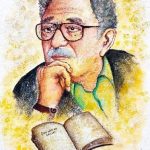... loading ...

... loading ...

کراچی کی حالت ایک جاں بلب مریض کی مانند ہے۔ اودے اودے ، نیلے نیلے ،پیلے پیلے معالج ’’ گردوں‘‘ سے قطار اندر قطار اُترے چلے آتے ہیں۔ سب کے نسخے اور نیتیں الگ الگ ۔ مریض بھلے ہی سخت جان ہو، مگر معالج لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہیں، ہر ایک موقع سمجھ کر مریض کا جو حصہ ہاتھ لگے جھپٹ پڑنے کو تیار ہے۔ گاہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ معالج ہیں یا بھیڑئیے؟ مختار مسعود کی آخری کتاب ’’حرفِ شوق‘‘ سے اِس ’’شوقِ علاج‘‘ کی گتھی سلجھتی ہے۔ مرحوم نے اپنے علی گڑھ کو یاد کرنے کے لیے کتاب لکھی ۔ کبھی رسول حمزہ توف نے اپنے داغستان کو اسی طرح یاد کیا تھا۔ سب کے دلوں میں ایک مخملی ڈبیا ہوتی ہے جہاں اُن کا بچین ، لڑکپن اور جوانی، بڑھاپے سے ہم آغوش ہو کر رومان انگیز چادریں اورڑھتی ہیں۔ حافظہ ،علامہ اقبال کا شعر مستعار لیتا ، فریاد کناں رہتا ہے:
ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو
مختار مسعود کی حیات کے’’ سفرِ نصیب‘‘ میں علیگڑھ کا پڑاؤ منزل کی مانند ہے، وہ اپنا وجود نوزائیدہ ملک میں سمیٹ لائے تھے ، مگر دل وہیں چھوڑ آئے تھے۔زندگی نے فراغت پائی تو دل کی مصروفیت بڑھ گئی۔ علیگڑھ یاد آیا اور بے طرح یاد آیا۔اہلِ کراچی کا معاملہ ذرا سا مختلف رہا۔ وہ قائدِ اعظم کے نقشِ پا پر چلتے چلتے وجود ہی نہیں دل بھی کراچی اُٹھا لائے تھے۔ علیگڑھ نے آخری تین برسوں میں قائدِ اعظم کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تقسیم کے بعد ادارے پر کیا بیتے گی، انتہا پسند ہندو انتقام پر اُتر سکتے تھے۔ مگر اہلِ کراچی ’’مہاجر‘‘ بنے تو یہ نہیں سوچا کہ جو وہ لے جارہے ہیں، اُس کے ساتھ کیا ہوگا اور جو چھوڑ جائیں گے ، اُس کے ساتھ کیا بیتے گی؟ہجرت کا راستاماتمی رنگ سے پیراستہ اور درد والم کے مرثیوں سے گونجتا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی سے تو اپنی کتابیں ہاتھ سے نہ چھوٹتی تھیں، زندگی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچی تو کتابوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا ، ایک حصہ دارالعلوم ندوہ کے نام ،تو دوسرا علیگڑھ کے لیے مخصوص کیا۔ ٹرک بھر کتابیں جارہی تھیں، دوڑتے ہوئے جاتے، ایک کتاب اُٹھاتے، کھولتے، پڑھتے واپس رکھ دیتے۔ یہ کتابیں نہیں ایک پوری زندگی تھی۔ اہل ِ کراچی پر یہ واقعہ بار بار بیتا۔ وہ جس گاڑی میں سوار ہوئے پیچھے رہ جانے والے دوڑے ہوئے آتے، گلے لگتے اور گلے لگائے رخصت کرتے ۔دونوں طرف زندگیا ں تھیں۔ دونوں کو امتحان سے گزرنا تھا۔ ہندوستان میں رہ جانے والوں کو باربار ہندؤںسے پاکستان جانے کا طعنہ سننا تھا۔ اور پاکستان آنے والوں کو’’ دھرتی کے بیٹوں‘‘ سے اپنے وجود کی سچائی منواتے منواتے اس طعنے کا بار بار سامنا کرنا تھا کہ کراچی ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اردو کے پروفیسر ، مرحوم شاعر راحت اندوری نے تو بھارت میں یہ کہنے کی ہمت جمع کرلی تھی کہ ’’کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے‘‘۔اہلِ کراچی کا معاملہ مختلف ہے، اُن پر قیادت کے نام پر ایسے قاتل ، خونی ، وحشی اور چنگیزی مزاج کے رہنما مسلط کیے گئے کہ وہ اس نوع کا مصرعہ کہیں تو ’’دہشت گرد‘‘ کہلانے لگیں۔
بات مختار مسعود کے ’’حرفِ شوق‘‘سے چلی تھی، سمتوں کا ٹوٹتے فسوں اور کراچی کے آوارہ رستوں کی طرح یہ بات بھی تہمتِ بے راہ روی کا شکار ہوسکتی ہے۔ سو’’ شوقِ آوارگی‘‘ سے کچھ دیر کو راہِ فرار لیتے ہیںاور’’ حرفِ شوق ‘‘کو پڑھتے ہیں، شاید کراچی کی گتھی سلجھ جائیـ، مختار مسعود علیگڑھ کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’سالہا سال سے جمعرات کے روز ہمارے یہاں ایک پیر مرد آواز لگاتے ہیں۔ آواز پُراثر شخصیت تاثر پزیر۔
ان کے لیے خیرات پہلے سے نکال کر رکھی جاتی ہے۔ میں انہیں اسکول کے دنوں سے جانتا ہوں اور ایم اے کے
سالِ آخر میں بھی میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان سے ہفتہ واری ملاقات میں ناغہ نہ ہو جائے۔ایک بار پانچ
چھے ہفتے تک وہ غیر حاضر رہے۔ گھر میں دبی زبان سے اس خدشے کا اظہار ہورہا ہے کہ شاید وہ پردہ کرگئے ہیں۔
جب اُن کی آواز دوبارہ سننے کو ملی تو سب کو بہت خوشی ہوئی ۔ انہوں نے سوال پوچھنے سے پہلے ہی وضاحت کردی
کہ وہ پاکستان گئے ہوئے تھے۔ وہاں دیکھا کہ کیا امیر اور کیا غریب، کیا مقامی اور کیا مہاجر، کیا حاکم اور کیا محکوم،
سب مانگنے میں مصروف ہیں۔ جہاں اتنے سائل اور طلب گار جمع ہوجائیں وہاں کسی درویش کا کیا کام ، چنانچہ
واپس آگئے‘‘۔
کراچی کو دیکھ لیں، منظر وہی ہے جو درویش نے ابتدا میں دیکھا تھا۔ ایسا نہیں کہ کچھ فرق واقع نہ ہوا ہو۔ تب پاکستان نوازئیدہ تھا، ابتدا تھی لوگ مانگ لیتے تھے، اب انتہا ہے مانگتے نہیںلوٹ لیتے ہیں۔لوٹنے والوں میں جھگڑا’’ حصہ بقدر جثہ‘‘ کا ہے۔ تب مانگنے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اب لوٹنے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے تو بس اتنا کہ امیر غریب ، مقامی مہاجر اور حاکم محکوم سے چلتے ہوئے بات وفاقی، صوبائی تک بھی نہیں ٹہری ۔ان کو ساتھ بٹھانے والے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے ہیں۔کبھی محمود وایاز نماز کے لیے ایک صف میں کھڑے ہوجاتے تھے، اب دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جی اُچاٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ حساب کتاب کی باتیں ’’چومنے چاٹنے‘‘ والے لے آتے ہیں۔ پھر اقتدار کی گھمن گھیریوں میں کھینچا تانی شروع ہوتی ہے تو ’’حساب کتاب ‘‘ کی باتیںاقتدار کے ’’ سہولت کاروں‘‘ کی ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ جیل سے لندن کے راستے بن جاتے ہیں۔ بلاول ہاؤس کے راحت کدوں میںعلاج معالجے شروع ہوجاتے ہیں۔ کراچی کا حرفِ شوق، لوٹ مار ہے۔ ہاں اس غم کو بانٹنے کے لیے کچھ’’ ردالی عورتیں‘‘ بھی رکھی گئی ہیں جو اس لوٹ مار پر گریہ زاری کرتی ہیں۔وفاقی وزراء کے مردانہ چہروں پر نہ جائیں، ان کی حرکتوں کو ٹٹولیں، یہ ’’ردالی عورتیں‘‘ان میں مل جائیں گی۔
آہ علیگڑھ پلٹنے والا درویش کہاں ہے؟ کراچی لوٹنے والے اہلِ کراچی کو خبر دیتے ہیں کہ وہ اس کی ترقی پر کمربستہ ہیں۔ بستۂ قفلِ ستم سے بندشوں کی داد ِ تمنا شاعر کی خواہش تو ہوسکتی ہے، مگر ڈوبنے والے ڈبونے والوں کو پیار سے دیکھنے لگیں تو موت پر زندگی کی تہمت دھری جائے گی، ہر اُلٹی چیز سیدھی نظر آئے گی۔ زوال کی ایک علامت فلسفۂ تاریخ میں یہ بھی ملتی ہے کہ قیدی اپنی زنجیروں سے پیا رکرنے لگتا ہے۔ وہی ڈوبنے والے ڈبونے والوں کو نگاہِ محبت سے دیکھتے ہیں۔ابھی لندن میں اینٹھتا ڈکراتا وہ شمر صفت کراچی کی جان چھوڑنے پر تیار نہیںکہ دوسرے کراچی کی جان کو آگئے۔کیا یہی ہمارا مقدر ہے؟ لندن کا عفریت انسانی جانوں کو لقمہ تر بناتا تھا، جوبچ گئے، اُن جانوں سے یہ اپنا سامان زندگی جمع کرنے پر تُلے ہیں۔ کراچی کے ہاتھ پہلے بھی کچھ نہیں آیا، اب بھی نہیں آئے گا۔مگر اہلِ کراچی پر ایک جبر مسلط ہے ، اُنہیں اپنی’’ ایسٹ انڈیا کمپنی‘‘ سے پیار کرنا ہے۔بات کہاں ختم ہوتی ہے، بس ورق تمام ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا کہ علیگڑھ کا درویش میرے کان میں سرگوشی کررہا ہے، آپ بھی سن لیں، غارت گروں کا اتفاق خوشخبری نہیں ہوتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔